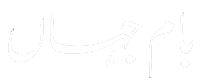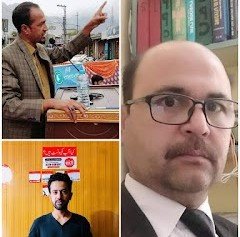یہ کیسا انصاف ہے جس نے 14 لوگوں سے جوانی اور والدین سے ان کے بڑھاپے کا سہارا چھینا، بچوں کو باپ اور بیوی کو شوہر سے جدا کر دیا اور اپنے کئے پر نادم بھی نہیں۔ بچے تعلیم سے محروم ہوئے اور والدین کا علاج نہ ہوسکا۔ انصاف دینے والوں نے اس کا ازالہ بھی نہیں کیا۔ بیوی نے بیوگی کی زندگی گزاری اور خود اپنی زندگی کے دس قیمتی سال کم ہوئے جو لوٹ کر پھر نہیں آئیں گے مگر داد رسی کا کوئی در نہیں جس پر دستک دی جائے اور انصاف کا کوئی ترازو نہیں، جس میں اس نقصان کو تول کر ازالہ کیا جاسکے۔
یہ سب کو معلوم تھا کہ ہنزہ علی آباد میں ایک عوامی احتجاج پر پولیس گردی کے بعد گرفتار کئے جانے والے سب بے گناہ ہیں۔ جن افراد کے قتل کے الزام میں ان کو گرفتار کیا گیا تھا ان کے لواحقین بھی پکارتے رہے کہ ان کے پیارے جن کے ہاتھوں مرے ہیں وہ یہ نوجوان نہیں بلکہ وہ ہیں جن کو شاباش ملی ہے۔ سرکاری فرانزک رپورٹ سے معلوم کرنا مشکل نہ تھا کہ مرنے والے کس بندوق کی گولی کا نشانہ بنے ہیں مگر شنوائی نمائشی تھی۔ جج سننے، سمجھنے اور دیکھنے سے قاصر تھے، فیصلہ پہلے سے طے شدہ تھا کہ ایسی مثالی سزا دے کر دوسروں کو سبق سکھایا جائے کہ کوئی پھر کبھی سر اٹھانے کی جرات نہ کر سکے۔
دلیل تھی نہ کوئی حوالہ تھا ان کے پاس
عجیب لوگ تھے بس اختلاف رکھتے تھے
گرفتار ہونے والوں پر کئے جانے والا تشدد اور ان کی چیخیں پاس بیٹھے منصب داروں کو تو سنائی نہیں دیں مگر دنیا بھر کے انسانی حقوق کے علمبرداروں نے سنیں۔ بے گناہ پابند سلاسل قیدیوں کی ماؤں نے مملکت خداد داد کے ہر بادشاہ، ہر حاکم، سپہ سالار اور منصف کے پیر پکڑے مگر دھتکارے گئے۔
ایک کے بعد دوسری حکومت کے اقتدار کا سورج غروب ہوا مگر ناکردہ گناہوں کی پاداش میں قید ہونے والوں کی آزادی کی نوید دینے والا سورج طلوع نہ ہوسکا۔ وعدے وفا نہ ہوسکے کسی عہد کا ایفا نہ ہوا۔ باباجان اور افتخار کربلائی کا نام زبان زد عام ہوا مگر ان کو انصاف نہ مل سکا۔

ہنزہ کے لوگوں نے دوسری حکومت کے اختتام اور تیسری حکومت کے لئے انتخابات سے قبل اپنے پیاروں کو زندان سے چھڑانے کا فیصلہ کیا۔ لوگ سمجھ گئے تھے کہ اس ملک کی جمہوریت میں لوگوں کی عزت صرف ووٹ کی وجہ سے ہے جو حکومت بنانے کے کام آتا ہے۔ ایک دفعہ حکومت بن جائے تو منتخب ہونے والے اپنی جنم دینے والی ماں کو بھی بھول جاتے ہیں۔ ہنزہ کے نوجوان، بزرگ، خواتین اور بچے علی آباد میں پاکستان کو چین سے ملانے والی شاہراہ ریشم پر دھرنا دے کر بیٹھ گئے اور اس وقت اٹھے جب ان کے ساتھ بے گناہ قیدیوں کی رہائی کا معاہدہ ہوا۔
2011ء میں ان نوجوانوں کی گرفتاری سے 2020ء میں رہائی تک کم و بیش ایک دہائی میں ایک پیڑھی پیوند خاک ہوئی، ایک نسل جوان ہوئی، ایک نئی پود دنیا میں آگئی۔ جن بچوں نے اپنی ماؤں کے گود میں یہ قصے سنے تھے وہ جوان ہوئے اور جو سکولوں اور کالجوں میں تھے عملی زندگی میں آچکے ہیں۔ نو سال تک جب کسی بات کا ذکر ہوتا رہے تو اس کا کچھ اثر تو انفرادی اور اجتماعی طور پر ہوتا ہے جس کا اظہار ہو یا نہ ہو مگر معاشرے کے مجموعی طرز عمل سے عیاں ضرور ہوتا ہے.

سماجی ناانصافی سے لوگوں کی اجتماعی سوچ میں تبدیلی کیسے آتی ہے، اس کا ادراک وہ کر ہی نہیں سکتے جنھوں نے اپنے ہاں نافذالعمل انگریزی قانون کو لاطینی اور فرانسیسی اصطلاحوں کی رٹا لگا کر پڑھا ہو۔ برصغیر میں جو قانون نافذ کیا گیا تھا اس کا مقصد ایک منصفانہ سماج کی تشکیل و قیام نہیں بلکہ انگریز آقا کی وفادار رعایا کا نظم و نسق تھا۔ آزادی کے بعد اگر سزا دینے کے لئے ایسا استعماری قانون بھی کم پڑ جائے تو ناانصافی کی ایسی مثال پھر کیا ہوسکتی ہے۔
سیاسی جبر کا معاشرے پر کیا اثرات ہوتے ہیں وہ سمجھ ہی نہیں سکتے جنھوں نے سیاسیات کے کثیر الجہت مضمون کو صرف مقابلے کا امتحان پاس کرنے کے لئے امریکہ کے صدارتی اور برطانیہ کے پارلیمانی نظام کو ازبر کر کے سمجھنے کی کوشش کی ہو۔
لوگوں کی سوچ کو محدود کرنے کی مصنوعی کوششوں سے بغاوت اور مزاحمت کے شعور سے تحت الشعور میں جاگزین ہونے کے عمل کوجو شہریوں کی ریاست سے بیگانگی پر منتج ہوتا ہے وہ کیسے سمجھ سکتے ہیں جن کی تربیت میں سوچنا، سمجھنا اور بولنا جرم اور صرف حکم بجا لانا ہی صلاحیت کا واحد معیار ہو۔
آوازیں خاموش کرکے نظام زندگی چلانے کے ماہرین سکوت کی آوازیں سن ہی نہیں سکتے۔ وہ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ آوازوں کے ترنم میں ہی زندگی ہے، خاموشی صرف موت کی علامت ہے اور موت کے بعد صرف حشر کا انتظار ہوتا ہے جو قبر کے سناٹے میں کیا جاتا ہے کسی جیتے جاگتے معاشرے میں نہیں۔

علی آباد میں احتجاج اور اس کو بزور قوت دبانے کی کوشش اور اس کے نتیجے میں بہنے والے خون کے دھبے دھونے کے لئے بے گناہ لوگوں کو پابند سلاسل کرنے سے چند لوگوں اور کچھ اداروں کی انا کی تسکین ضرور ہوئی ہوگی مگر انسانی سوچ کے دھارے اپنی رفتار سے بہتے رہنے سے کوئی نہیں روک سکا۔
اس دوران لوگوں کا یہ گمان کہ قانون کی حکمرانی ایک منصفانہ معاشرے کی بنیاد ہے، متزلزل ہوگیا۔ ایک ہی رات میں عدالت سجا کر 14 شہریوں سے ان کی آزادی چھین کر 40 سے 90 سال کے لئے سپرد زندان کرنے سے قانون کی حکمرانی کے بجائے انصاف کی طاقتور کے سامنے بے بسی عیاں ہوگئی۔
دس سال میں گھر گھر ہونے والی بات چیت، سکولوں، کالجوں کے کلاس روم اور اسٹاف روم، عدالتوں کے بار روم، پریس کلبوں، ہوٹلوں، بسوں اور ویگنوں میں بیٹھے مسافروں میں پروان چڑھے مکالمے اور بحث و تمحیص آہستہ آہستہ بتدریج ایک جگہ مجتمع ہوئی تو اس کا نتیجہ علی آباد کے دھرنے کی شکل میں سامنے آیا۔ لوگوں کا ایک ہجوم جس میں وہ بھی تھے جن کے عزیزوں پر قتل کا الزام تھا اور وہ بھی جن کے عزیز قتل ہوئے تھے، وہ سب دس سال پہلے شاید سیاسی طور پر الگ الگ ہوں مگر آج سب متفق تھے کہ احتجاج کرنے والوں کو سزا دی جائے اور گولی چلانے والوں کو شاباش، یہ سراسر ناانصافی ہے۔
دھرنے کے دوران جو باتیں ہوئیں، جو تقاریر ہوئیں اور وہ گفتگو جو نہ ہوسکی مگر سمجھ سب کو آگئی وہ بھی اس طرز عمل کو احاطہ کئے ہوئے تھی جو 1947ء سے اب تک کسی نہ کسی صورت جاری ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ خلق خدا کی اپنی ماں ریاست سے اس شکایت کو جرم گرداننے کے بجائے مکالمہ بنایا جائے اور ازالہ کیا جائے مگر ایسا ہونا مشکل نظر آتا ہے۔ آج بھی بے گناہ لوگوں کو قید میں رکھ کر دس سال ضائع کرنے پر تاسف کا اظہار کرنے کے بجائے رہائی کا احسان جتلانے کی جتن جاری ہے جس میں ہر کس و ناکس اپنی کارکاردگی پر داد کا طلبگار ہے۔
آج اسیران ہنزہ جیل سے رہا ہوگئے، مبارک! مگر ہم نہیں جانتے کہ ان کی یہ رہائی اس عدالتی فیصلے کو ایک طرف رکھ کر عمل میں آئی ہے یا فیصلہ اپنی جگہ برقرار ہے اور رہائی مشروط۔ مگر ہنزہ کے عام لوگ ایک بات جانتے ہیں کہ نہ ان اسیران کی سزا میں قانون کا عمل دخل تھا نہ رہائی میں۔ یہ ایک نا انصافی تھی جو عوامی مزاحمت سے ختم ہوئی۔
یہ کالم پہلے ‘ہم سب’ میں شائع ہوا تھا جسے ہم مصنف کی اجازت سے یہاں دوبارہ شائع کر رہے ہیں. تمام تصاویر بام جہاں کے نامہ نگار رحیم خان، عابد طاشی اور آصف کی ہیں.
علی احمد جان سماجی ترقی اور ماحولیات کے شعبے سے منسلک ہیں۔ وہ کالم نویس اورگھومنے پھرنے کے شوقین ہیں، کو ہ نوردی سے بھی شغف ہے۔