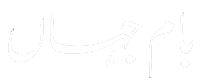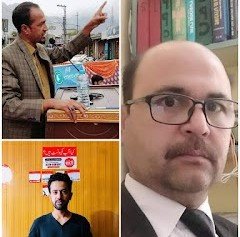عاصم سجاد اختر

میں گزشتہ بیس برس میں انگنت احتجاجی کیمپوں میں شریک ہوا ہوں مگر اسلام آباد پریس کلب کے باہر تازہ ترین بلوچ لاپتہ افراد کے لواحقین کے کیمپ میں جاتے ہی میرے اندر ایک ایسا بھاری پن ابھرا جو میں نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا۔ سمی دین مجھے دیکھتے ہی کھڑی ہوئی اور کیمپ میں آنے پر شکریہ ادا کیا۔ میں نے فوراً جواب دیا کہ شکریہ کس بات کا، انتھک اور بے انتہا تکلیف دہ جدوجہد تو آپ لوگ کر رہے ہیں، ہم تو صرف آپ کا وقتا فوقتاً ساتھ دینے آتے ہیں۔ سمی دین نے پھر مجھے کہا کہ میرا والد ڈاکٹر دین محمد تو 2009ء سے لاپتہ ہے، ہم اس وقت سے آپ کو دیکھتے آرہے ہیں۔ اس وقت بچے تھے، اب ہم خود بالغ ہو گئے ہیں۔

باقی ملاقات میں سمی اور ان کے دیگر ساتھیوں نے مجھے تذلیل کی داستان سنائی جس کا سامنا ان کو کمیشن برائے جبری گمشدہ افراد کے آخری اجلاس میں کرنا پڑا۔ کیسے ان کو کمیشن کے چیئر پرسن، ریٹائرڈ جسٹس جاوید اقبال کے تلخ الفاظ برداشت کرنے پڑے، کیسے انہوں نے کئی برس سے ایسی بے شمار کارروائیاں دیکھیں جو کہ مکمل طور پر لاحاصل رہیں۔ یہ ساری باتیں میں سنتا رہا، اور سوچتا رہا کہ ایک اور لاپتہ افراد کے کیمپ کی امداد کس طرح کی جائے، کس صحافی دوست سے رابطہ کیا جائے کہ وہ آ کر تھوڑی بہت کوریج کر لے، کس سیاسی لیڈر کو پیغام بھیجا جائے کہ وہ پانچ دس منٹ لواحقین کے ساتھ وقت گزار لے، کس دوست سے کہا جائے کہ وہ پردیس سے آئے ہوئے ان بلوچوں کے لیے ایک وقت کے کھانے کا انتظام کرے۔
لیکن اس سے بھی زیادہ میں اس بات پر سوچتا رہا کہ یہ سب کچھ کتنے عرصے سے چل رہا ہے۔ کہ میں نے بھی اپنی آنکھوں سے سمی دین، ماہرنگ اور دیگر کتنے بلوچ بچیاں اور بچوں کو ساری جوانی لانگ مارچوں، کیمپوں اور نام نہاد کمیشنوں میں گزارتے ہوئے دیکھا۔ میں خود اس جد و جہد میں تھوڑا بہت حصہ ڈالتے ڈالتے، کالم لکھتے اور سڑکوں پر نعرے لگاتےا ور دہائیاں گزار چکا۔
احساس عجیب چیز ہے۔ احساس ہی ہے جو کہ کسی زندہ انسان کو دوسرے کسی انسان کے ساتھ مشکل وقت میں کھڑا کرواتا ہے۔ احساس ہمیں خوف سے بھی لڑ نے کی ہمت دلواتا ہیں۔ لیکن احساس تھکاتا بھی ہے۔ اگر مجھے اس بات کے احساس نے تھکایا کہ میں کتنے عرصے سے بلوچ لاپتہ افراد کے لواحقین کی کوششوں کی حمایت کرتا رہا ہوں، تو ان کے اندر دل و دماغ میں کیا چلتا ہوگا؟ سمی دین نے مجھے اس حوالے سے دو جھلکیاں دکھائیں۔ 12 سالہ جد و جہد کا تھوڑا سا ذکر کرتے ہوئے اس نے مجھے کہا کہ بندہ وہی باتیں، وہی نعرے، وہی کاوشیں کرتے کرتے کبھی سن ہو جاتا ہے۔
لیکن پھر ساتھ ہی اس نے اپنے آپ کو یاد دلایا کہ وہ اب ڈاکٹر محمد دین بلوچ کی بیٹی کے علاوہ بلوچوں کی نہ ختم ہونے والی حقوق کی تحریک کی لیڈر بھی بن چکی ہے۔ اپنا سر مزید بلند کرتے ہوئے اس نے مجھے کہا کہ حال ہی میں برمش، حیات اور دیگر کتنے ایسے واقعات کو بلوچ نوجوان خاموشی سے برداشت کرتے رہیں گے؟ یقیناً بلوچ نوجوانوں کی ایک اور نسل اب کیمپوں اور ریلیوں میں آ رہی ہے۔ سمی دین اور ماہرنگ کے والد کی اغواء کاریوں کے دور میں جو لوگ متحرک تھے اب ان کی جگہ ایسے نوجوانوں نے لے لی ہے جنہوں نے بہت چھوٹی عمر میں ریاستی جبر کی بدترین اشکال دیکھیں۔ اور سمی دین اور ماہرنگ کو دیکھتے دیکھتے ایک نئی نسل جد و جہد کے لیے تیار ہو گئی ہے۔
یہ کہانی ویسے تو ہے بہت پرانی۔ بلوچ نوجوان ہر عہد میں شعور سے لیس اور اپنی سرزمین، وسائل، کلچر اور سیاسی خودمختاری کے حوالے سے آواز اٹھاتے رہے ہیں۔ جبکہ ریاست پاکستان کے تحفظ اور ”قومی سلامتی“ کا چرچا کرنے والے بلوچ آوازوں کو شروع دن سے دباتے رہے ہیں۔ کشیدگی اور سختی کبھی کم ہوتی تو کبھی زیادہ ہوتی ہے لیکن ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ چنانچہ اب بلوچوں کی ایک نئی نسل کے اندر پھر کچھ کرنے، بولنے اور زور دینے کا رجحان نظر آتا ہے، ۔
شاید اس باریہ نوجوان اپنے لیے بھی کچھ حاصل کریں اور خداداد پاکستان میں آئے روز بڑھتی ہوئی اندھیر نگری میں تھوڑی سی روشنی کا باعث بنیں گے۔ یا شاید 75 سال سے بلوچوں اور اس دیگر مظلوم اقوام پر جاری ظلم و جبر کے پہاڑ ٹوٹتے رہیں گے۔ در حقیقت سوال ہے ہی یہہی کہ اپنے پیاروں کی بازیابی، عزت و نفس کی بحالی اور پھر اسٹیبلشمنٹ کو لگام دینا کیا صرف بلوچوں کی ذمہ داری ہے؟
پاکستان میں ترقی پسند سیاست کی آج جتنی ضرورت ہے شاید پہلے کبھی نہیں تھی۔ کچھ بھی اگر یہاں بہتری آنی ہے تو بلوچوں، سندھیوں، پشتونوں، کشمیریوں، گلگت بلتستانیوں، سرائیکیوں اور دیگر قوموں کی جدوجہد کو جوڑنے کے ساتھ ساتھ محنت کشوں، عورتوں، مذہبی اقلیتوں اور سماج کے ہر اس پرت کو جوڑنا ہو گا جو کہ جبر و استحصال کا شکار ہے۔ آج سے چند دہائیاں قبل، جب ایشیا و افریقہ میں سامراج مخالف تحریکیں عروج پر تھیں، اور جب بائیں بازو کے انقلابی مزدور کسان راج کے خواب دیکھتے تھے، تب بلوچوں اور دیگر مظلوم حلقوں کی جدوجہد مشترک تھی۔
ترقی پسند سیاست کی علامت نیشنل عوامی پارٹی میں میر غوث بخش بزنجو اور خیر بخش مری کے ساتھ ساتھ سندھ کے جی ایم سید اور حیدر بخش جتوئی، پختونخوا کے ولی خان اوعبدلصمد خان اچکزئی، بنگال کے مولانا بھاشانی اور دیگر کئی نامور شخصیات موجود تھیں۔ مظلوم اقوام کو پنجاب اور کراچی کے محنت کشوں اور طلبا تحریکوں کے ساتھ جوڑنے کی بھی شعوری کوششیں ہوتی تھیں۔
کئی لوگوں کے لیے ترقی پسند سیاست اس دور کے ساتھ ہی ختم ہو گئی۔ یقیناً 1980ء کے بعد پاکستان سمیت دنیا بھر میں بائیں بازو بالخصوص اور ترقی پسند نظریات بالعموم پچھے دھکیلے گئے ہیں۔ اگر اسٹیبلشمنٹ اتنی ڈھٹائی سے جبری گمشدگیوں کو ایک پالیسی کے طور پر چلائے ہوئے ہے تو اس کی ایک بڑی وجہ جمہوری قوتوں کی کمزوری ہے، اور اس ضمن میں بائیں بازو کا مرکزی دھارے کی سیاست میں تقریباً نہ ہونا بہت معنی خیز ہے۔ تاہم یہی مقتدرہ ترقی پسند سیاست کی ابھرتی ہوئی نئی لہر کو تقویت بھی دے رہی ہے۔
جبری گمشدگی کی پالیسی کے تحت مشرف دور میں بلوچوں کے ساتھ ساتھ ان ”جہادیوں“ کو بھی نشانہ بنایا گیا جو کہ مقتدر قوتوں کے اپنے پالے ہوئے تھے۔ آج سندھی، پشتون، کشمیری، حتیٰ کہ مذہبی مسلک کے حوالے سے بھی بندے اٹھائے جاتے ہیں۔ جس کے بھی گھر سے بندہ اٹھا کر لاپتہ کیا جاتا ہے اس کے اندر ایک ایسا احساس پیدا ہوتا ہے کہ وہ اپنے جیسے دوسروں کی تکلیف کو اندر سے سمجھتا ہے۔ کراچی کے اردو بولنے والے اور پنجاب کی سرزمین پر بھی اس سلسلے کے پھیلاؤ نے واضح کر دیا ہے کہ مقتدرہ کسی کو نہیں بخشتی اگر وہ شخص یا تنظیم حکمرانی کے نظام کی بنیادوں کو تھوڑی سی بھی تنقید کا نشانہ بناتا ہے۔
2017ء میں اغواء ہونے والے پنجابی بلاگرز کی غلطی بھی یہی تھی کہ وہ بلوچ اور دیگر لاپتہ افراد کی بات اور مجموعی طور پر ”قومی سلامتی“ کے ریاستی بیانیہ کو چیلنج کرتے تھے۔ چار سال گزرنے کے بعد پنجاب کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے احتساب کا مطالبہ کرنے والی آوازیں بڑھی ہیں، بے شک ایسی آوازوں کو دبانے کے لیے اغوا سمیت دیگر حربے جاری ہیں۔ بلوچ اور دیگر مظلوم خطوں کے نوجوان نسل آج کچھ کرنے اور بولنے پر تیار ہوئی ہے تو پنجاب میں بھی نوجوانوں میں ترقی پسند نظریات و سیاسی جد و جہد کا رجحان بڑھا رہا ہے۔ یقیناً پاکستان کی کل 23 کروڑ آبادی میں سے 65 فیصد نوجوانوں کی اکثریت آج بھی مقتدرہ کے پروپیگنڈا سے متاثر ہے اور شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہونے کا مظاہرہ کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال جتنے بھی ہیں، پنجاب کے اندر ترقی پسند نوجوانوں کا عنصر مقتدرہ کو چبھ ضرور رہا ہے۔
کیمپ کے دوسرے روز کے اختتام پر خبر آئی کہ 2018ء سے لاپتہ طلبا رہنماء فیروز بلوچ کو بازیاب کیا گیا ہے۔ گزشتہ ہفتوں میں ایسی زیادہ خبریں آئی ہیں۔ اور سمی دین کے بقول ایک بھی لاپتہ فرد بازیاب ہونا بہت بڑی کامیابی ہے۔ بے شک ہزاروں ابھی بھی غائب ہیں، مگر فیروز سمیت چند لوگ بھی واپس نہ آتے اگر مسلسل جدوجہد جاری نہ رہتی۔ در اصل یہ بلوچ نوجوان صرف اپنی جد و جہد نہیں کر رہے ہیں۔ جب وہ اپنے پیاروں کی بازیابی کا مطالبہ کرتے ہیں تو وہ ان تمام انسانوں کی بات کر رہے ہیں جن کو فرانس کے مشہور حریت پسند دانشور فرانز فینن نے ”افتادگان خاک“ کہا تھا۔
حکمرانی کا فرسودہ نظام قائم رکھنے کے لیے ایسی آوازوں کو دبانے سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے جو نفرت کی سیاست ترک کر کے تمام قوموں، محنت کشوں، صنفوں اور مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والوں کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سمی دین اور میرا سفر اس احساس کی وجہ سے بار بار ایک ہوتا ہے جو کہ ایک انسان کو دوسرے انسان کے ساتھ کھڑا کرتا ہے، بے شک وہ ایک دوسرے کو کبھی نہ ملے ہوں۔ ہماری زندگیاں گزر ہی جائیں گی، مگر آنے والی نسلوں کو امن، رواداری اور برابری کے خواب منتقل ضرور کریں گے۔
یہ مضمون سب سے پہلے ‘ہم سب’ میں شائع ہوا۔
عاصم سجاد اختر مصنف، سیاسی کارکن، اور استاد ہیں وہ قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں پڑھاتے ہیں اورانگریزی اخبار ڈان اور اردو میگزین ‘ہم سب’ میں کالم لکھتے ہیں۔